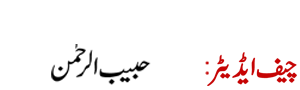تاريخ کا ارتقاء اور انتقام؛ تحرير: خالد تھتھال

جالو جالو آگُن جالو، پوتھے پوتھے آگُن جالو، دھیکے دھیکے آگُن جالو ، يعنی جلاؤ جلاؤ آگ جلاو ( روشنی کرو) ، راستے راستے( ہر راستے) آگ جلاؤ، سمت سمت (ہر سمت) آگ جلاؤ
یہ مشرقی پاکستان کی نیشنل عوامی پارٹی کے راہنما مولانا بھاشانی تھے۔ جنرل یحیٰ خان کا زمانہ تھا اور انتخابات سر پر آ گئے تھے۔ اس وقت مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اپنے سوشلزم کے نعرے کو مذہبی حلقوں کی مخالفت کی وجہ سے سوشلزم سے اسلامی سوشلزم اور پھر مساوات محمدی کے نام پر مارکیٹ کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے پاکستان چھوڑا۔
ساٹھ کی دہائی کے وسط میں میرے گاؤں کے کچھ لوگ معاش کی تلاش میں برطانیہ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو معاشی طور پر بہت بدحال تھے، جنہوں نے اپنی ایک آدھ بیگھ زمین کو بیچا، ایجنٹ کو ادائیگی کی اور نکل پڑے۔ ان دنوں مشہور تھا کہ یہ جو ولایت جا رہے ہیں یہ پانچ سال بعد آئیں گے۔ ہر کسی کوان پر ترس آ رہا تھا کہ یہ بیچارے ایک ایسےپردیس جا رہے ہیں جہاں سے پانچ سال پہلے واپس نہیں آ پائیں گے کیونکہ یہی بات ایجنٹ نے بتائی تھی کہ یہ لوگ پانچ سال تک ولایت میں ہی رہیں گے۔ اب ان پانچ سالوں میں پتہ نہیں کون جیے گا اور کون مرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا کوئی عزیز مر بھی گیا تو منہ دیکھنا تو درکنار، نہیں مرنے والے کی موت کی خبر بھی جلد از جلد ہفتے بعد ملے گی اور پھر اپنے عزیز کے مرنے کی خبر سننے کے بعد بھی یہ واپس نہیں آ سکیں گے بلکہ وہیں رہیں گے۔
جو لوگ مقابلتاً معاشی طور پر بہتر تھے، اُن کے منہ سے ایک اور فقرہ جو ان دنوں سنا جاتا تھا ، وہ یہ تھا کہ باہر کی چُپڑی سے گھر کی روکھی سوکھی بہتر ہے۔ لہذا اُن گھروں سے کوئی بھی برطانیہ نہ گیا۔
اور پھرپانچ سال گزر گئے اور غریب غربا برطانیہ سے واپس لوٹے۔ پاکستان میں قیام کے دوران اُن کی دھوپ سے جلی رنگت سرد آب و ہوا کی وجہ سے اب سرخ و سپید ہو گئی تھی، کیرالین کی قمیضیں، خوبصورت جرسیاں اور اُن کی پیسوں سے بھری جیبیں ہر کسی کے منہ میں پانی لانے کیلئے کافی تھیں۔ اب ہر کوئی ولایت جانا چاہ رہا تھا۔ لیکن ساتھ یہ بھی خبر تھی کہ ولایت بند ہو گیا، جس سے مراد تھی کہ اب وہاں کا داخلہ بند ہے۔ لوگ دوسری ممالک کی طرف نکل پڑے، میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو 1970 میں خوابوں کی سرزمین کی تلاش میں نکل پڑا۔
مجھے موسیقی کا بہت شوق تھا، خواجہ خورشید انور میرا عشق تھا۔ آج بھی ان کا کمپوز کیا کوئی گانا سنتا ہوں تو دل بھر آتا ہے۔ میں نے بہت تلاش کی کہ خورشید انور کے گانوں کے ریکارڈ خرید پاؤں ۔ لیکن دو ای پی ( extended play) کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ ابھی پاکستان میں ایل پی بننے نہیں شروع ہوئے تھے۔ میں نے پشاور سے ایک دوکان پر چرخی (spool) میں گانے ”بھروائے“۔
پشاور سے ایک ٹرک میں بیٹھ کر کابل پہنچا۔ یہ ظاہر شاہ کا کابل تھا، جو اپنے ہمسایہ ملک ایران کی جدیدیت سے بہت متاثر تھا۔ کابل کے بس سٹاپ پر بہت سے لڑکیاں سکرٹ پہنے دیکھیں۔

بسوں سے سفر کرتا مشہد پہنچا، جہاں میں امام علی رضا کے مقبرے کے پیچھے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ میرے پاس بٹوے سے تھوڑے بڑے سائز کا بیگ یا پرس تھا، جس کے ساتھ ایک تنی تھی، جس گلے میں ڈال کر م میں نے اُسے قمیض کے اندر رکھا ہوا تھا، اُس میں میرے پیسے اور پاسپورٹ تھے۔ چنانچہ گلے میں لٹکا یہ پرس مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میں سوٹ کیس کو سرہانے کے طور پر استعمال کرتے سویا۔
وہاں سرائے میں بہت سے مرد اور خواتین زائرین بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔سب عورتوں نے سکرٹ پہنا ہوا تھا اور ہر کسی نے اوپر کالے رنگ کی شال اوڑھی ہوئی تھی جسے چادُر کہتے ہیں۔ مشہد سے تہران تک بس کا سفر تھا، تی بی تی نام کی بسیں دو دن سے کم وقت میں تہران تک کا سفر طے کرتی تھیں۔ تہران میں لڑکیوں نے منی سکرٹ پہنے ہوئے تھے، شال کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ رضا شاہ پہلوی کا ایران تھا۔ تہران سے آگے کا سفر ٹرین سے کیا ۔
ریلوے سٹیشن پر بہت زیادہ پاکستانی کولمبس دیکھنے کو ملے۔ ان کی اکثریت دیہات سے تعلق رکھتی تھی۔ ایجنٹ نے انہیں دھاری دار قمیض اور پاجامہ یہ کہہ کر سلوانے کو کہا تھا کہ رات کو کسی چادر کو تہبند کے طور پر لپیٹ کر نہیں سونا، بلکہ اس دھاری دار سوٹ کو پہننا، اسے سلیپنگ سوٹ کہتے ہیں۔ لیکن سلیپنگ سوٹ کے آرام دہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی میں سفر کر رہے تھے۔
ایک صاحب اپنے بوٹوں سے بہت نالاں تھے کیونکہ ان کے بقول بوٹ انہیں تنگ کرتے تھے۔ دیکھنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے بوٹ الٹے پہنے ہوئے تھے۔ ہمارے دیہات میں موچی کی بنائی ہوئی جوتی کا کوئی الٹا سیدھا نہیں ہوتا، جس جوتی کو چاہیں جس پاؤں میں پہن لیں۔ ترکی کی ایک ٹرین میں ایک پاکستان ملے جو کافی عرصہ سے برطانیہ مقیم تھے۔ انہوں نے ان پاکستانی بھائیوں کیلئے گوریلے کی اصطلاح وضع کی ہوئی تھی۔
اوسلو پہنچ کر جو بھی ملنے آئے ان سب کو میرے سفر کی روائیداد جاننے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کیا میں کوئی گانے لے کر آیا ہوں۔ جواب اثبات میں پا کر ہر کوئی اپنا ٹیپ ریکارڈر لے کر گھر آ رہا تھا۔ وہ ہفتے کا روز ، ایک دن انتظار کر کے سوموار کے روز ایک نارویجن خاتون سے اخبار پڑھوا کر کام کی خالی جگہ کا پوچھا۔ پہلی فیکٹری میں ہی کام مل گیا۔ اور زندگی کا سفر آگے بڑھنے لگا۔
ناروے ایک انتہائی سرد ملک ہے۔ اس لمحے جب میں یہ لکھ رہا ہوں۔ اوسلو میں درجہ حرارت منفی بیس ہے۔ شمالی ناروے کا تو اللہ ہی حافظ ہو گا۔ ناروے میں میری ساری زندگی سمر(summer) کے انتظار میں گزر گئی۔ لیکن وہ سمرِ موعود کبھی نہیں آیا۔ اور جب کبھی احساس ہوا کہ اب سمر آنے والا ہے تو پتہ چلا کہ سمر تو گزر بھی چکا ہے۔ اب اگلی سمر کا انتظار کیا جائے۔ میرے ایک نارویجن دوست کے بقول ناروے میں دو ونٹر (موسم سرما) ہیں۔ ایک سفید اور دوسرا سبز۔ سفید سے مراد ایسا ونٹر جس میں چاروں طرف برف ہوتی ہے اور سبز وہ ونٹر جب سبزہ تو ہوتا ہے لیکن سردی پھر بھی محسوس ہوتی ہے۔
اب جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے بہت کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہوں، ان سالوں میں سب کچھ بدل گیا۔ ہم کبھی ناروے سے خط لکھا کرتے تھے جو ہفتے سے بھی زیادہ عرصہ میں پاکستان پہنچا کرتا تھا۔ اس نیلے رنگ کے کاغذ کو ایروگرام کہا جاتا تھا، اس پر ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہ ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی قیمت میں شامل تھا۔ جب کبھی پتہ چلتا کہ کوئی اپنے گاؤں والا پاکستان جا رہا ہے تو ہر کوئی رخصت کرنے کے بہانے رقعہ لے آتا تھا کہ یہ میرے گھر والوں کو دے دینا کیونکہ اس رقعے نے دو دن میں گھر پہنچ جانا تھا۔ اب خط نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ حد یہ کہ ناروے میں ڈاکخانے بند ہو چکے ہیں۔ ان کو مختلف فوڈ سٹورز کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں لوگوں کے پارسل آتے ہیں، اور انہیں نپٹانا فوڈ سٹورز کے ملازمین ہی کا کام ہے۔ آپ کو ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ فلاں فوڈ سٹور میں آپ کا پارسل آیا ہوا ہے۔
کبھی مقامی طور پر ٹیلیفون کی ضرورت پڑی تو ٹیلیفون بوتھ کا سہارا لیا جاتا تھا، جسے ہمیں کھوکھے کہا کرتے تھے۔ اس میں ایک کرونا ڈال کر تین منٹ دورانیئے کا فون کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر کسی کے گھر ٹیلیفون موجود تھا۔ پاکستان فون کرنا اس قدر مہنگا ہوتا تھا کہ تین منٹ کی کال کیلئے چند گھنٹوں کی تنخواہ چلی جاتی تھی۔ اور پھر اس کا حل ٹیلیفون کارڈز کی صورت میں آیا۔ مقابلے کی وجہ سے قیمتیں دھڑا دھڑ نیچے گرنی شروع ہوئی اور ہم پردیسیوں کو پاکستان ٹیلیفون کرنے کی سہولت میسر آ گئی۔
اور پھر ایک دن میرا ایک بزنس مین دوست گلے میں ایک بکس سا لٹکایا ہوا گھر آیا۔ یہ موبائل تھا۔ وہ ہر کسی کو اس کا نمبر دے رہا تھا کہ آئندہ اسے اس پر فون کیا جائے لیکن جونہی سب کو پتہ چلا کہ اس نمبر پر فون کرنے سے فون کرنے والے کی کھال ادھڑ جاتی ہے تو کسی نے بھی فون کرنے کی ہمت نہ کی۔ میرا یہ دوست بہت چھچھورا تھا۔ گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا، میں نے مبارک باد دی۔ اس نے کہا کہ مجھے مبارکباد دے دی ہے۔ اب میری بیوی کو بھی ہسپتال میں مبارکباد دو۔ اور وہ موبائل اسی کے پاس پڑا ہوا ہے۔ مجھے فون کیے بغیر چارہ نہ تھا۔
میں بہت عرصہ موبائل خریدنے سے انکار کرتا رہا۔ گھر میں فون ہے، کام کی جگہ پر فون ہے، اگر کسی کے ہاں گیا ہوں تو وہاں فون ہے۔ لہذا مجھ سے رابطہ کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ مجھ سےصرف ان دس پندرہ منٹوں میں رابطہ نہیں ہو سکتا جب میں کہیں سفر کر رہا ہوں۔ لیکن میں تو اتنا اہم نہیں ہوں اور نہ ہی ان پندرہ منٹوں میں میرے ہاتھوں سے کوئی بزنس کانٹریکٹ چلا جائے گا۔ لیکن مجھے بیٹے نے مجبور کیا اور میں نے اسے موبائل لے کر دے دیا، کیونکہ اُس کے سبھی ہم جماعتوں کے پاس موبائل تھا۔
یاد آیا ایک پیجر نام کی بھی چیز ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی بیٹے کو خرید کر دی تھی۔ اس میں کوئی میسج قسم کی چیز تھی۔ اب اس کی تفصیل یاد نہیں رہی۔
میں نے بہت دیر بعد موبائل خریدا۔ اور مجھے صرف اس بات سے غرض تھی کہ اس سے فون کرنا، ریسو کرنا اور ایس ایم ایس کرنا ہے۔ لہذا جب موبائل میں کیمرہ آیا تو مجھے بہت عجیب لگا کہ جب کیمرہ پہلے ہی موجود ہے تو اس کی ایکسٹرا قیمت ادا کیوں کروں۔ اور آج حال یہ ہے کہ میں نے سونی ایکسپیریا 2 خریدا ہی اس لیے تھا کہ اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے۔ اور حد یہ کہ اگر آپ ٹیلی فوٹو گرافی کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں ایکسٹرا لینز بھی لگا سکتے ہیں۔
مجھے موبائل کے اندر انٹرنیٹ کی پنگے سے بھی بہت گلہ تھا کہ یہ لوگوں کو لوٹنے کیلئے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے۔ لیکن کروں، مجھے وائبر اور وٹس ایپ اور آئمو جیسی سہولیات کیلئے انٹر نیٹ والے فونز کی جلد ہی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور اس وقت میں تین موبائل لیئے بیٹھا ہوا۔ ایک سونی ایکسپیریا ٹو، ایک ایل جی فور اور ایک چینی ہواوے سات۔
میں جب ناروے آیا تو چرخی والے ٹیپ ریکارڈر کا بہت زور تھا۔ نیدر لینڈ کی فلپس کمپنی مارکیٹ پر چھائی ہوئی تھی۔ بعد میں کیسٹس آئیں جو شروع میں تو آواز کی کوالٹی اچھی نہ تھی لیکن جلد ہی انہوں نے چرخی والے ٹیپ ریکارڈر کو باہر دھکیل دیا۔ اور پھر وہ بھی آہستہ آہستہ نئی چیزوں کی جگہ چھوڑ گئیں۔
کبھی ایل پی ریکارڈ بھی ہوا کرتے تھے۔ اوسلو میں ریکارڈ کی دوکانیں ہر سودو میٹر کے فاصلے پر ہوا کرتی تھیں۔ ایل پی کی جگہ سی ڈی آئی نے لے لی، لیکن اب موسیقی کی ڈاؤن لوڈ کرنے کا زمانہ ہے۔ پورے اوسلو میں شائد اس وقت موسیقی کی صرف دو دوکانیں بچی ہیں۔
شائد کوڈک، اگفا، گیورٹ کے لفظ کافی دوستوں کیلئے شناسا نہ ہوں گے۔ یہ ایسی کمپنیاں تھیں جو فوٹو گرافی کے لیے فلمیں بناتی تھیں۔ آپ کیمرے میں فلم ڈال، فوٹو بنوانے کے بعد فوٹو گرافی کی دوکان پر جاتے تھے کہ وہ فلم کو”دھونے“ کے بعد فوٹو پرنٹ کر دیں۔ اب کہیں فوٹو گرافی کی دوکانیں نظر نہیں آتیں۔ پتہ نہیں انہیں کس کی نظر لگ گئی۔
کبھی میں نے دو مہینوں کی تنخواہ سے اپنے وقت کا مہنگا ترین ریڈیو اس امید پر خریدا کہ اس سے پاکستانی ریڈیو کی عالمی سروس سے اردو گانے سن سکوں۔ لیکن اس میں چرڑ چرڑ کا اس قدر شور ہوا کرتا تھا کہ یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ کونسا گانا چل رہا ہے۔ آج میرے پاس کم از کم تیس دیسی ٹی وی چینل ہیں۔ جب میری پاکستانی بھائی پی ٹی وی یا جیو سوپر پر کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں اسی لمحے وہ میچ سکائی سپورٹس پر دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے پاس بھی وہی جیو، وہی اے آر وائی، وہی ژی ٹی وی، سونی، سونی میکس وغیرہ سب کچھ ہے۔
میں نے 2012 میں Toyota Prius Hybrid یہ سوچ کر خریدی کہ یہ بجلی اور پٹرول دونوں سے چلتی ہے، حالانکہ اس وقت نسان کی الیکٹرک کار آ چکی تھی، لیکن وہ مکمل چارج ہونے کے بعد 120 کلو میٹر سے زیادہ نہیں چل پاتی تھی، لہذا میری مجبوری تھی کہ ایک ایسی کار ہو کہ اگر بجلی ختم ہو جائے تو پٹرول کے سہارے منزل تک پہنچ پاؤں۔ لیکن اگلے سال ہی امریکہ کی ٹیسلا اپنی الیکٹرک کار مارکیٹ میں لے آئے جو مکمل چارج ہونے کے بعد تقریباََ پانچ سو کلو میٹر کا سفر طے کرتی ہے۔
میں جب بھی کوئی چیز خریدتا ہوں تو اگلے سال اس کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایک سال انتظار کیوں نہ کیا، کہ بعد میں آنے والی چیز پہلی کے مقابلے میں اس قدر بہتر ہوتی ہے کہ لگتا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔
اب ٹی وی کو ہی لے لیں، میں نے دس سال پہلے جاپان کمپنی جے وی سی کا بہت اعلی ٹی وی خریدا وہ اس وقت سونی اور پینا سونکس وغیرہ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ لیکن اگلے سال ہی مارکیٹ میں فلیٹ سکرین والے ٹی وی آ گئے۔ لیکن مجھے ایک گونہ تسلی تھی کہ ان کے رنگ اس قدر اچھے نہ تھے جیسے میرے ٹی وی کے تھےجتنے میرے ٹی وی کے تھے۔ اور میرے لیے ٹی وی میں سب سے اہم خوبی اُس کے رنگ ہوتے ہیں۔
لیکن پھر ہائی ڈیفینیشن ٹی وی آ گیا۔ اور پھر full high definition ٹی وی آیا۔ میں نے 2011 میں نیا فلیٹ خریدا اور اس وقت کا سب سے مہنگا سونی ٹی وی خریدا جس میں رنگوں کی خوبصورتی اور تصویر کے واضح ہونے کا تو کوئی جواب نہ تھا، اس میں انٹرنیٹ، یو ٹیوب، سکائپ وغیرہ سب سہولتیں تھیں۔ میں نے سوچا اس سے آگے کسی ٹی وی میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی کی انتہا ہے۔ لیکن پھر ایل جی اور سامسنگ کا مقابلہ اور super high definition, اور hyper definition ، یہ سب میرے ٹی وی کو شرما رہے تھے۔ سوچ رہا تھا کہ اپنا ٹی وی کسی کو اونے پونے بیچ کر انہیں خرید لوں کہ k4 کی ٹیکنالوجی آ گئی جس کی تصویر کی کوالٹی عام ہائی ڈیف ٹی وی سے چار گنا بہتر تھی۔ اور اب ایل جی والے Oled ٹیکنالوجی والا ٹی وی لے آئے ہیں۔
میں ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار سے بہت تنگ آ چکا ہوں جو میرے گھر میں موجود اچھی خاصی چیزوں کو پھینکنے اور نئی چیزیں خریدنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ منحوس سرمایہ داری نظام بھی عجیب چیز ہے۔ یہ صرف آپ کی ضرورتیں پوری ہی نہیں کرتا بلکہ آپ کی لیے نت روز نئی ضرورتیں پیدا بھی کرتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے میں اپنے گاؤں میں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتا تھا اور مجھے گرمی تنگ نہ کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ ہاتھ والا پنکھا جھلا لیا کرتا تھا۔ مجھے اس سرمایہ داری نظام نے بجلی کا پنکھا خریدنے پر مجبور کیا۔ اور وہ جب خرید لیا تو مجھے احساس دیا کہ مجھے ایر کنڈیشنر کی ضرورت ہے۔

عجیب دنیا ہے، کبھی کارل مارکس، فریڈرک اینگلز، لینن و ٹراٹسکی ہوا کرتے تھے۔ پلیخانوف کی تاریخ میں فرد کا کردار سٹڈی سرکلز میں پڑھی۔ ایک روزا لکسمبرگ بھی ہوا کرتی تھی۔ یورو کمیونزم کا بھی ذکر ہوا کرتا تھا۔ کوئی سمیر امین اور ارنسٹ مانڈیل بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک امریکی ٹراٹسکائٹ کا نام اب ذہن سے اتر گیا ہے جس کی کتاب the mandate of heaven پڑھی تھی جس نے چیز مین ماؤ پر تنقید کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اگر ماؤ ٹھیک ہے تو مارکس غلط تھا اور اگر مارکس صیح تھا تو ماؤ غلط تھا۔ کیوبا میں اب بھی کامریڈ فیڈل کاسترو موجود ہے۔ ہیوگو شاویز گزر گیا ہے، وہ پیرو کا کسان رہنما ہیوگو بلانکو تھا، وہ ساندنیستا کا تھومس بورگے تھے۔ فورتھ انٹرنیشنل بھی بنی تھی جن کے نزدیک اپنے آپ کو سوشلسٹ معاشرے کہنے والے اصل میں ورکرز سٹیٹس نہیں ہیں بلکہ degenerated worker’s states ہیں۔ اور پھر وہ برطانیہ میں ٹونی کلف ہوا کرتا تھا جو سوشلسٹ ورکرز پارٹی کا رہنما تھا جو فورتھ انٹرنیشنل سے اتفاق نہیں کرتا تھا، وہ ان معاشروں میں رائج نظام کوstate capitaism کہتا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں گئے۔ اور پتہ نہیں ہمارے بعدکتنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور چل بسیں گے۔ لیکن یہ گلا سڑا نظام جسے دنیا سرمایہ داری کہتی ہے یہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔
میرا انگریزی کا پروفیسر اکثر ایک نظم سنایا کرتا تھا جس میں سکندر اعظم اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنے کے تین دن بعد قبرستان میں جا کر مجھے پکارنا۔ ماں ویسے ہی کرتی ہے لیکن جونہی وہ سکندر کو پکارتی ہے تو قبروں کے اندر سے بہت سی آوازیں آتی ہیں۔ ماں کہتی ہے، میں نے اپنے بیٹے سکندر سے بات کرنی ہے۔ وہ آوازیں جواب دیتی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ماں ہی ہے، اور ہم بھی اپنے وقتوں کے سکندر تھی لیکن تو کس سکندر کا پوچھ رہی ہے۔
میں اب بھی کبھی اکیلا بیٹھتا ہوا تو ماضی میں غوطے کھانے لگتا ہوں۔ اور میرے دماغ میں ایک شور سا مچ جاتا ہے
سرخ ہے، سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے۔
سرمایہ داری نظام گل سڑ چکا ہے۔
گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔
جالو جالو آگُن جالو، پوتھے پوتھے آگُن جالو، دھیکے دھیکے آگُن جالو
لیکن میں سر جھٹک کر جلد ہی حال میں واپس آ جاتا ہوں کیونکہ ایک تو اب پُلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے دریافت کر لیا ہے کہ تاریخ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے ہی یہاں تک پہنچی ہے۔ کسی غلام داری سماج کا ذکر سنا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیسے آہستہ سے بدل کر تاریخ کا حصہ بن گیا، سرمایہ داری نے کیسے دبے پاؤں جاگیرداری کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب سرمایہ داری ہے جو آہستہ آہستہ ایک منصفانہ معاشرے کی طرف بڑھ رہی ہےجس میں انسانوں کی بنیادی ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ سکینڈے نیویا کے معاشرے اس کی واضح مثال ہیں۔ لیکن اگر کسی جلد باز نے تاریخ میں سیندھ لگانے کی کوشش کی تو تاریخ نے کچھ عرصہ بعد ہی اپنا انتقام لے لیا ہے۔
Related News

میں نیشنل ازم پہ کاربند کیوں ہوں ؟ (تشدد و عدم تشدد ) تحریر مہر جان
Spread the love“مسلح جدوجہد دشمن کو زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے” (بابا مری) کبھی کبھی ایساRead More

عملی اور نظریاتی رجحان انسانی ارتقاء میں کتنا کارگر – کوہ زاد
Spread the loveانسان کا نظریاتی ہونا ایک بہت ہی عمدہ اور اعلی اور بہت ہیRead More